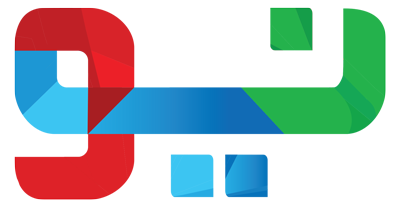ایک عام پاکستانی کے گھر میں جتنے بکھیڑے ہیں اگر انہیں 100 خانوں میں تقسیم کریں تو سیاست اور جمہوریت کا صرف ایک خانہ ہے، باقی 99 دوسرے سماجی مسائل سے بھرے پڑے ہیں۔ آئیے! آج انہی 99 خانوں میں سے ایک عام پاکستانی کی آپ بیتی پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ وہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ پیدا تو اپنے اپنے گھر ہوئے لیکن پلے بڑھے اکٹھے۔ گھروں میں زیادہ روٹی نہ تھی اور سہولتیں بھی بہت کم تھیں۔ اسی لیے تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر راولپنڈی کے ایک دفتر میں سِول کلرک بابو لگ گئے۔ کالی سفید کتابیں پڑھنے سے ہلکا سا شعور جاگ چکا تھا۔ یہ شعور چیز ہی ایسی ہے، ذرا سی بھی ہوتو بہت تنگ کرتی ہے، اُس کو بھی جس کے اندر موجود ہو اور انہیں بھی جو شعور کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ ان دونوں کا بھی یہی مسئلہ نمبر ایک تھا کہ ہڈیوں کے جوڑجوڑ میں رچی صدیوں پرانی خاندانی غربت اور جہالت کو ختم کیا جائے اور ترقی کی جائے۔ اُن میں سے ایک نے ’’کتابی باتوں‘‘ کے چکر میں آکر ڈگریوں کو بلندی اور عزت کی وجہ جانا۔ کلرکی کے ساتھ ساتھ میٹرک کے بعد ایف اے، بی اے اور پھر انگریزی میں ایم اے کرلیا۔ دوسرے نے زندگی کی حقیقت میں چھپی چڑیل کو دیکھ لیا اور جان لیا کہ وہ اِسے دولت سے ہی ہلاک کرسکتا ہے۔ لہٰذا اُس نے امیر بننے کے لیے یورپ جانے کی کوشش شروع کردی۔ ایک دن آیا کہ اُن دونوں میں سے ایم اے پاس دوست نے راولپنڈی کے ایک سرکاری کالج میں انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے اپنے نئے کیریئر کا آغاز کیا جبکہ عین انہی دنوں دوسرے کو برطانیہ کا ویزا مل گیا اور وہ ایئرپورٹ جاپہنچا۔ جب لیکچرر دوست نے سوکھی گیلی کے ساتھی اور اپنے بچپن کے جگری دوست کو الوداعی جپھا ڈالا تو برطانیہ جانے والے دوست نے اپنی جیب سے ایک قلم نکالا اور کہا کہ ’’یار تم جانتے ہوکہ میں نے یہ قلم اُس وقت لیا تھا جب میٹرک کا امتحان دینا تھا لیکن پھر مجھے تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ تم نوکری کے ساتھ پڑھتے رہے مگر میں نوکری کے ساتھ ساتھ ویزے کی تلاش میں رہا۔ میں آج یہ قلم اپنی چاندنی جیسی دوستی کی نشانی کے طور پر تمہیں دیتا ہوں‘‘۔ پھر ایک کا جہاز برطانیہ روانہ ہوگیا اور دوسرا اومنی بس میں بیٹھ کر کالج آگیا۔ ہزاروں فٹ بلند فضائوں میں اُس دوست اور زمین پر موجود اِس دوست کے ایک ہی جیسے جذبات تھے۔ دونوں کبھی
الگ نہیں ہونا چاہتے تھے مگر اُس ظالم شعور نے انہیں الگ الگ کردیا جس نے اُن میں ترقی کرنے کی ’’بھَڑکی‘‘ لگائی۔ لیکچرر دوست نے اُس دن سے روزانہ اُسی قلم سے اپنے طالبعلموں کی حاضری لگانی اور ذاتی خطوط لکھنے شروع کردیئے۔ وہ ’’استادی سیاست‘‘ کے باوجود ترقی کرتا ہوا لیکچرر سے پروفیسری تک پہنچ گیا۔ اُس کے سرکاری گریڈ اور عمر میں بہت تبدیلی آگئی لیکن وہ قلم تبدیل نہ ہوا۔ وہ اُسی طرح ہر روز اُسی قلم سے اپنے طالبعلموں کی حاضری لگاتا۔ چار برس کالج میں پڑھنے والا ہر طالبعلم اِس پروفیسر سے سوال کرتا کہ آخر اس قلم میں کیا بات ہے کہ وہ اِسے تبدیل نہیں کرتے؟ پروفیسر مسکراتے اور چپ ہو جاتے مگر زمانے کا دھکا لگنے سے چہرے میں دھنستی ہوئی آنکھیں ویسی ہی ٹین ایج والی کھلنڈری ہو جاتیں جیسی لڑکے ہر اُس خاتون سے بھی اپنے تعلق کی ایسی ویسی باتیں گھڑکر یاروں کو سناتے ہیں جو اُنہیں کبھی کبھار بیٹا کہہ کر تندور سے روٹیاں منگوانے کے لیے دسترخوان اور پیسے دیتی ہو۔ اس قلم کا ذکر آتے ہی پروفیسر کا ہاتھ ماتھے پر اُلٹے لیٹے ’’کالے سفید اینگلو بالوں‘‘ پر اس طرح پھرتا جیسے ہمسائی آنٹی کے ساتھ ٹیکسی پر بڑی مارکیٹ جانے سے پہلے چھوکرے گلی کی نُکر والی نائی کی دکان میں باربار کنگھی کرکے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہیں۔ یارانے کی اِن عمروں میں کھائے ہوئے کچے پکے بیر بھی بڑھاپے میں کھائے جانے والے اعلیٰ نسل کے سیب سے زیادہ لـذیذ محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل یہی وابستگی پروفیسر کی قلم کے ساتھ تھی۔ برس ہا برس بعد اُن پروفیسر کے ایک طالبعلم جو اَب خود ایک ٹھیک ٹھاک افسر ہے، کو پرانی یاد ستائی تو اُس نے اپنے اُنہی پروفیسر کا کھوج لگانے کی ٹھانی۔ سرکاری ملازم کا سراغ ریٹائرمنٹ تک تو مل جاتا ہے، اُس کے بعد وہ کٹی پتنگ ہوتا ہے مگر اُن کے شاگرد کی سچی لگن رنگ لے آئی اور وہ پروفیسر تک جاپہنچا۔ شاگرد کی توقعات کے برخلاف ان بوڑھے ترین دنوں میں پروفیسر اپنی اولاد کی اولاد سے انجوائے نہیں کررہے تھے بلکہ زندگی کے زہریلے دنوں کو اُسی طرح نگل رہے تھے جیسے انہوں نے اپنی جوانی کی زندگی میں مشقت کی تھی۔ وہ اب راولپنڈی کے ایک نجی ٹیوشن سنٹر میں انگریزی پڑھا رہے تھے۔ اُن سے ملنے کے بعد شاگرد نے اپنی مایوسی کے اِس پہلے حصے کو خاموشی سے پار کیا اور پوچھا ’’سَر! کیا وہ قلم اب بھی آپ کے پاس ہے؟‘‘ شاگرد کو ایسا لگا جیسے اُس کے سامنے موہنجودڑو کے قبرستان سے کوئی پرانا مردہ نکل کر آگیا ہو۔ پروفیسر کے زنگ آلود گلے سے نکلا ’’ہوا یہ کہ میرے جس دوست نے مجھے وہ قلم تحفے میں دیا تھا وہ برطانیہ جاکر خوب سیٹل ہوگیا۔ ہمیں یقین تھا کہ ہماری دوستی ہمارے ڈی این اے میں شامل ہوچکی ہے۔ اُس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنالیا اور میں نے اُس کے بیٹے کو اپنا بیٹا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بچوں کی شادی نے ہماری دوستی کو نیا رنگ اور نئی عمر دی ہے۔ بیٹی لندن اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ تمہیں معلوم ہے اُن دنوں رابطے کا ذریعہ خط ہی تھا۔ وہاں جاکر بیٹی نے خطوط کے ذریعے مجھ سے رابطہ رکھا۔ شروع میں، میں نے غور نہیں کیا لیکن رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہوا کہ اُس کی تحریروں میں نئی دلہن اور گورے ملک کی شوخیاں نہیں ہیں۔ میں سمجھا کہ اجنبی جگہ کو اپناتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اُس کی لکھی لائنوں میں بہت ہی پھیکا پن آتا گیا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اُن دنوں اتنی دور کے دیس میں براہِ راست رابطہ بھی ممکن نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ بیٹی کے خط آنے کی رفتار مہینوں سے کود کر برسوں میں چلی گئی۔ اس وقت تک میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جان چکا تھا۔ بعض لوگ یہاں سے یورپ جیسے پڑھے لکھے اور انسان دوست معاشروں میں جاکر آباد تو ہوجاتے ہیں مگر اُن کا ’’اندر امیگریشن‘‘ نہیں لے سکتا اور پہلے جیسا ہی وحشی رہتا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی پہلے دن سے ہی شوہر کے گھر کی جنت میں نہیں بلکہ عقوبت خانے میں داخل ہوئی تھی۔ میری امید میری بیٹی کا سسر اور میرا جگری دوست تھا۔ وہ تو وہیں موجود تھا لیکن پھر ایسا کیوں ہورہا تھا؟ میں کانپ جاتا۔ معاملات بگڑتے گئے۔ ایک دن دروازہ کھٹکا۔ میں باہر نکلاتو وہی بیٹی جسے میں نے دلہن بناکر جہاز پر سوار کرایا تھا، اپنے چہرے اور جسم پر جگہ جگہ ’’شوہری طاقت‘‘ کے نشان لیے کھڑی تھی۔ اُس نے سب کچھ بتایا اور شاید کچھ چھپایا بھی۔ بس آخر میں اتنا کہا کہ ’’میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ کہتا ہے نہ تو میں تمہیں گھر آنے دوں گا اور نہ ہی طلاق دوں گا، صرف ذلیل کروں گا‘‘۔ بیٹی کو ایشین کمیونٹی نے ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کرکے دیئے اور وہ میرے پاس آگئی۔ پھر مقدمے بازی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ آخرکار طلاق ہوگئی۔ اُس کا شوہر اور میرے جگری یار کا بیٹا جب ہمارے گھر سے طلاق کے کاغذوں پر فائنل دستخط کرکے جانے لگا تو میں نے اُسے کہا ’’ٹھہرو ایک چیز لیتے جائو‘‘۔ وہ حیرانگی سے رکا۔ میں نے اندر سے اُسے وہی قلم لاکر دیا اور کہا کہ ’’یہ قلم اب واپس لے جائو‘‘۔ اس طرح میں نے وہ قلم واپس کردیا ہے۔
میں نے وہ قلم واپس کردیا ہے